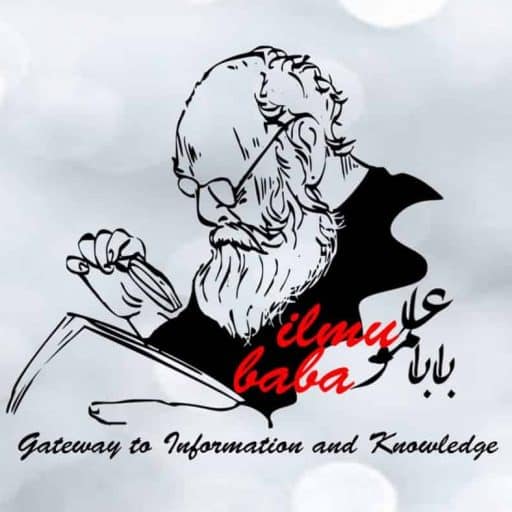علامہ اقبال کی غزل جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں کی تشریح
علامہ اقبال کی اس غزل میں انسان کی باطنی عظمت، عشق کی حقیقت اور روحانیت کی گہرائیوں کو بیان کیا گیا ہے۔ اقبال نے اس غزل میں محبت، روحانیت، خودی اور انسان کی اصل حقیقت کو بہت خوبصورتی سے پیش کیا ہے۔ انہوں نے عشقِ حقیقی کو ایک ایسا جواہر قرار دیا ہے جو ظاہری دنیا کے خزانوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ ہر شعر میں اقبال نے مختلف پہلوؤں سے انسان کی روحانی حقیقت کو اجاگر کیا ہے، اور اس کی قوت و تاثیر کو پیش کیا ہے۔ یہ غزل اقبال کے فلسفۂ عشق، خودی اور معرفت کی غماض ہے، جس میں وہ بتاتے ہیں کہ انسان کے اندر لامحدود طاقت اور عشقِ الٰہی کی شمع جلانے کی صلاحیت موجود ہے، جو دنیا کی تمام تر حقیقتوں کو روشن کر سکتی ہے۔ اس غزل میں اقبال کا پیغام یہ ہے کہ انسان اپنی داخلی دنیا کی روشنی کو پہچانے اور اس کی حقیقت کو دنیا کے سامنے لائے۔ اس آرٹیکل میں علامہ اقبال کی غزل جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں کی تشریح پیش کی جا رہی ہے۔ مزید تشریحات کے لیے ہماری ویب سائیٹ علمو ملاحظہ کیجیے۔ اور بارہویں جماعت کے مزید اردو نوٹس ملاحظہ کرنے کے لیے یہاں کلک کیجیے۔
شعر 1: جنہیں میں ڈھونڈھتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں۔ وہ نکلے میرے ظلمت خانۂ دل کے مکینوں میں
تشریح: اس شعر میں علامہ اقبالؔ نے انسانی باطن کی عظمت اور روحانی سفر کے اصل مرکز کی طرف اشارہ کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جنہیں وہ آسمانوں، زمینوں، یعنی ظاہری دنیا اور خارجی کائنات میں تلاش کرتا رہا، وہ حقیقت میں اس کے دل کے اندر، اس کی روح کے گہرے گوشوں میں موجود تھے۔ یہاں “ظلمت خانۂ دل” سے مراد وہ قلب ہے جو غفلت، جہالت، اور مادیت کے پردوں میں چھپا ہوا ہے۔ اقبال اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خدا، حق، سچائی، یا اعلیٰ روحانی حقیقت کی تلاش انسان کو باہر نہیں بلکہ اپنے اندر کرنی چاہیے۔ یہ ایک صوفیانہ تصور ہے جو قرآن، حدیث، اور تمام عرفانی روایتوں میں موجود ہے کہ:۔ “من عرف نفسہ فقد عرف ربہ“۔ یعنی (جس نے اپنے نفس کو پہچانا، اس نے اپنے رب کو پہچانا)
اقبال خودی کی تلاش اور اس کی تربیت پر زور دیتے ہیں۔ وہ انسان کو اپنی عظمت، اپنی پوشیدہ قوتوں، اور روحانی بلندیوں سے آشنا کروانا چاہتے ہیں۔ اس شعر میں وہ کہتے ہیں کہ اصل خزانہ باہر نہیں، ہمارے اندر ہے۔ اگر انسان اپنے دل کے اندھیروں کو دور کر لے، تو وہ ان حقائق کو پا سکتا ہے جن کے لیے وہ دنیا میں سرگرداں پھرتا ہے۔
شعر 2: حقیقت اپنی آنکھوں پر نمایاں جب ہوئی اپنی۔ مکاں نکلا ہمارے خانۂ دل کے مکینوں میں
تشریح: اس شعر میں علامہ اقبال روحانی خود آگاہی اور انسان کی باطنی عظمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ جب اُس پر اس کی اپنی حقیقت، اس کا جوہر، اس کی باطنی شناخت روشن ہوئی تو اسے یہ ادراک ہوا کہ جو کچھ وہ باہر تلاش کرتا رہا — یعنی “مکاں” (ساری مادی کائنات) — وہ سب تو پہلے ہی اس کے دل کے اندر موجود تھا۔ “خانۂ دل کے مکینوں” سے مراد وہ لطیف روحانی صفات، افکار، اور احساسات ہیں جو انسان کے دل و دماغ میں بسی ہوئی ہیں۔ علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کے مطابق، انسان معمولی نہیں بلکہ ایک کائنات ہے۔ اس کا دل نہ صرف محسوسات اور جذبات کا مرکز ہے بلکہ اسرارِ کائنات اور الہٰی تجلیات کا بھی حامل ہے۔ یہ شعر دراصل اس عرفانی تجربے کی نمائندگی کرتا ہے جس میں انسان کو “توحید” کا شعور حاصل ہوتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ حق، کائنات، ذات، سب کچھ اس کے اپنے اندر ہے۔ اقبال کے نزدیک جب انسان اپنی خودی کو پہچان لیتا ہے، تو وہ ایک ایسی حقیقت تک پہنچتا ہے جو خارجی دنیا سے کہیں زیادہ وسیع اور گہری ہے۔ اقبال کا یہ شعر نہ صرف روحانی بیداری کی طرف دعوت ہے بلکہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ جو لوگ خود کو جان لیتے ہیں، وہی اصل میں دنیا کو جاننے کی اہلیت رکھتے ہیں۔
شعر 3: اگر کچھ آشنا ہوتا مذاق جبہ سائی سے۔ تو سنگ آستان کعبہ جا ملتا جبینوں میں
تشریح: اس شعر میں علامہ اقبال بندگی کے جوہر، عاجزی، اور حقیقی عبادت کے مفہوم کو بیان کر رہے ہیں۔ “جبہ سائی” یعنی سجدہ کرنا، اور “مذاق جبہ سائی” سے مراد ہے کہ کوئی سجدہ کس نیت اور شعور کے ساتھ کرتا ہے۔ اگر سجدے میں حقیقتاً عاجزی، خلوص، اور عرفان ہو تو وہ ہر شے کو قابلِ تعظیم بنا دیتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر انسان کو سجدے کی روح سے آشنائی حاصل ہو جائے، تو وہ کعبہ کے دروازے پر پڑے ہوئے پتھر کو بھی سجدہ کرنے کے لائق سمجھے گا۔ یہ پتھر ظاہراً بے جان ہے، لیکن چونکہ وہ مقامِ مقدس پر ہے، اور قربِ حق میں ہے، اس لیے اس میں بھی ایک روحانی عظمت موجود ہے۔ اقبال کے نزدیک عبادت صرف جسمانی حرکت نہیں بلکہ روحانی بیداری کا عمل ہے۔ محض رسمی سجدے کچھ معنی نہیں رکھتے جب تک کہ دل میں اخلاص، فنا، اور حق کی تلاش نہ ہو۔ اگر سجدہ کرنے والا بندہ اپنی انا، غرور اور نفس کی دیواروں کو گرا دے، تو وہ ہر شے میں نور دیکھنے لگتا ہے — حتیٰ کہ ایک پتھر میں بھی۔ یہ شعر علامتی طور پر اس بات کی بھی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو چیزیں دنیاوی نظر میں بے قیمت ہیں، وہ روحانی شعور کی نظر میں بہت قیمتی بن جاتی ہیں۔ اصل قیمت نظر میں نہیں، نظر کے انداز میں ہے۔
شعر 4: کبھی اپنا بھی نظارہ کیا ہے تو نے اے مجنوں۔کہ لیلیٰ کی طرح تو خود بھی ہے محمل نشینوں میں
تشریح: اقبال اس شعر میں ایک نہایت اہم اور فکر انگیز پیغام دیتے ہیں۔ وہ صوفیانہ رنگ میں خطاب کرتے ہوئے مشہور عاشق “مجنوں” کو مخاطب کرتے ہیں، جو اپنی محبوبہ لیلیٰ کی محبت میں دیوانہ تھا۔ شاعر سوال کرتا ہے کہ “اے مجنوں! تُو نے کبھی خود کو دیکھا ہے؟” — یعنی تُو دوسروں کے حسن و جمال پر فریفتہ ہے، لیکن اپنی ذات کی عظمت سے غافل ہے۔ “محمل نشینوں” میں ہونا لیلیٰ کی عزت، وقار اور شان کا اظہار ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ تُو خود بھی ویسی ہی رفعتوں کا حامل ہے، بس تجھے اپنی حقیقت کا شعور نہیں۔
یہ شعر اقبال کے فلسفہ خودی کی ایک اعلیٰ ترجمانی ہے۔ وہ بارہا انسان کو اس کی اپنی ذات کے عرفان کی دعوت دیتے ہیں، کہ جس طرح وہ دوسروں میں خوبصورتی، عظمت یا روحانی حسن تلاش کرتا ہے، ویسی ہی یا اس سے بلند تر حقیقت خود اس کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ شعر دراصل انسان کو خود شناسی، خود اعتمادی، اور باطنی عظمت کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ اگر انسان دوسروں کی ظاہری خوبیوں سے ہٹ کر اپنی روحانی حقیقت کا عرفان حاصل کرے، تو اسے معلوم ہوگا کہ وہ خود کتنا باکمال ہے۔
شعر 5: مہینے وصل کے گھڑیوں کی صورت اڑتے جاتے ہیں۔ مگر گھڑیاں جدائی کی گزرتی ہیں مہینوں میں
تشریح: یہ شعر عشق کی جذباتی شدت اور انسانی احساسات کی نفسیاتی کیفیت کو بڑی نفاست سے بیان کرتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ جب محبوب قریب ہو، وصال نصیب ہو، تو وقت پر لگا کر اڑ جاتا ہے۔ اُس وقت کی قدر و قیمت بہت ہوتی ہے، مگر وہ لمحے ایسے گزرتے ہیں جیسے پل بھر ہوں۔ اس کے برعکس جب جدائی کا وقت آتا ہے، جب فراق کی آگ دل کو جلاتی ہے، تو ہر لمحہ مہینے بلکہ صدیوں جتنا طویل محسوس ہوتا ہے۔ یہ وقت کے نسبتی (relative) ہونے کا احساس شاعر نے بڑی سادگی سے بیان کیا ہے، جو نہ صرف عشق کے تناظر میں بلکہ انسانی جذبات کے ہر دائرے میں سچائی رکھتا ہے۔ یہ شعر محبوب سے قربت کی لذت اور فراق کی اذیت کو واضح کرتا ہے۔ یہاں علامہ اقبال نے اپنے فلسفیانہ طرز کو ایک نرم عشقیہ لہجے میں بدل کر قاری کو وہ احساس دلایا ہے جو ہر عاشق کی حالت ہوتی ہے: وصل تیزی سے گزر جاتا ہے، اور فراق کبھی ختم نہیں ہوتا۔ یہی وقت کی کیفیت عشق کو لازوال بناتی ہے، کیونکہ عاشق کو وہ لمحے جو محبوب کے ساتھ گزرے، پوری زندگی میں سب سے قیمتی لگتے ہیں، اور اس کی جدائی عمر بھر کا بوجھ۔
شعر 6: مجھے روکے گا تو اے ناخدا کیا غرق ہونے سے۔ کہ جن کو ڈوبنا ہو ڈوب جاتے ہیں سفینوں میں
تشریح: اس شعر میں اقبال نے تقدیر، عزم، اور روحانی جرأت کی بات کی ہے۔ شاعر “ناخدا” سے مخاطب ہے، جو کسی بھی کشتی میں بیٹھے لوگوں کو بچانے والا ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر میرا مقدر ڈوبنا ہے، تو تُو بھی مجھے نہیں بچا سکتا، کیونکہ جنہیں ڈوبنا ہوتا ہے، وہ محفوظ ترین جگہوں پر بھی ڈوب جاتے ہیں۔ یہ شعر قضا و قدر، قسمت اور روحانی تسلیم و رضا کا درس دیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ انسان کی حریت فکر اور خودی کی بلندی کو بھی سراہتا ہے۔ اقبال اس شعر کے ذریعے یہ پیغام دیتے ہیں کہ:
موت و حیات، کامیابی و ناکامی — سب کچھ ایک الٰہی نظام کا حصہ ہے۔
انسان کو خوف سے بلند ہو کر جینا چاہیے۔
جو دلیر ہوتے ہیں، وہ خطرات کے باوجود آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ انجام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
یہ شعر ان لوگوں کے لیے بھی حوصلہ افزا ہے جو زندگی میں کسی خطرے یا تبدیلی سے ڈرتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ بچنے کی ضمانت ظاہری حفاظتی تدابیر میں نہیں، بلکہ انسان کے ارادے، ایمان، اور عزم میں ہے۔
شعر 7: چھپایا حسن کو اپنے کلیم اللہ سے جس نے۔ وہی ناز آفریں ہے جلوہ پیرا نازنینوں میں
تشریح: یہ شعر قرآنی واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جب حضرت موسیٰ نے اللہ سے اُس کا جلوہ دکھانے کی خواہش کی، اور اللہ نے فرمایا: “تم مجھے نہیں دیکھ سکتے”۔ اور جب پہاڑ پر تجلی ہوئی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ بے ہوش ہو گئے۔ اقبال کہتے ہیں کہ وہ ذات جس نے اپنے حسن کو حضرت موسیٰ جیسے جلیل القدر نبی سے بھی چھپا لیا، وہ ذات ناز و جمال کی انتہا ہے۔ یہاں “ناز آفریں” اور “جلوہ پیرا” جیسی ترکیبیں اس حسنِ الٰہی کی طرف اشارہ کرتی ہیں جو ہر جمالِ دنیاوی سے بلند تر ہے۔ اقبال حسنِ حقیقی اور جمالِ الٰہی کی بات کرتے ہوئے اس حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں کہ دنیا کے تمام ظاہری حسن دراصل اسی حسنِ مطلق کا عکس ہیں۔ وہ اس بات کو خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ جو ذات موسیٰ سے بھی اپنا جلوہ چھپا گئی، وہ باقی حسینوں کے بیچ سب سے منفرد، کامل اور پوشیدہ ہے۔ یہ شعر عشقِ حقیقی، حسنِ الٰہی، اور انسانی نگاہ کی محدودیت کا عرفانی انداز میں اظہار ہے۔
شعر 8: جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موجِ نفس ان کی۔ الٰہی! کیا چھپا ہوتا ہے اہلِ دل کے سینوں میں
تشریح: یہاں اقبال “اہلِ دل” یعنی صاحبانِ معرفت و بصیرت، صوفیاء یا مردانِ حق کی روحانی طاقت کو بیان کرتے ہیں۔ “شمعِ کشتہ” (بجھی ہوئی شمع) ایک علامت ہے — مردہ دل، مایوس انسان، یا بجھا ہوا جذبہ۔ اور “موجِ نفس” (سانس کی لہر) علامت ہے اہلِ دل کی تاثیر، ان کے کلام، دعا یا روحانیت کی۔ شاعر حیرت سے پوچھتا ہے کہ اہلِ دل کے سینوں میں کیا قوت، کیا اسرار اور کیسا نور چھپا ہوتا ہے کہ ان کی سانس کی بھی ایسی تاثیر ہے جو مردہ دل کو زندہ، بجھی ہوئی شمع کو روشن، اور اندھیرے کو روشنی میں بدل سکتی ہے۔ یہ شعر روحانی قیادت، اندرونی روشنی، اور عرفان کی قوت کا ادبی اظہار ہے۔ اقبال یہاں انسان کی باطنی دنیا کی وسعتوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو لوگ “دل” کی حقیقت سے آشنا ہو جائیں، وہ خالق کے نور سے متصل ہو جاتے ہیں، اور دوسروں کی زندگیاں بدلنے کی طاقت رکھتے ہیں۔
شعر 9: تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی۔ نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں
تشریح: یہ شعر صوفیانہ تعلیمات اور سماجی شعور کا نچوڑ ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ “دردِ دل” جو کہ محبت، ہمدردی، انسانیت اور روحانی آگاہی کا نام ہے، وہ دولت یا دنیاوی شان و شوکت سے حاصل نہیں ہوتا۔ بلکہ یہ ان فقیروں، درویشوں، اور اہلِ دل کی صحبت سے ملتا ہے جنہوں نے دنیا کی ظاہری چمک دمک کو ترک کر کے دل کی دنیا کو اپنایا۔ “فقیروں کی خدمت” صرف ظاہری خدمت نہیں بلکہ ان سے سیکھنا، ان کی صحبت اختیار کرنا، ان کی سادگی، محبت، اور روحانی گہرائی سے اثر لینا مراد ہے۔ یہ شعر اقبال کی اس فکر کو ظاہر کرتا ہے کہ اصل علم و عرفان، اصل انسانیت اور اصل روحانی عظمت نہ محلات میں ہے، نہ تاج و تخت میں، بلکہ ان درویشوں کے پاس ہے جنہوں نے دل کو جگایا، نفس کو دبایا، اور حقیقت کو پایا۔
شعر 10: نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی، ارادت ہو تو دیکھ ان کو۔ یدِ بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں
تشریح: یہ شعر بھی صوفیائے کرام اور اہلِ دل کی شان پر ہے۔ “خرقہ پوش” وہ لوگ ہیں جو ظاہراً سادہ، درویش، فقیر نظر آتے ہیں۔ اقبال کہتے ہیں کہ ان کے خستہ حال لباس، اور خاموش چال کو دیکھ کر دھوکہ مت کھاؤ۔ اگر ان سے سچی عقیدت ہو، تو دیکھو کہ وہ اندر سے کتنی بڑی طاقت کے مالک ہیں۔ “ید بیضا” حضرت موسیٰ کا وہ معجزہ تھا جس میں ان کا ہاتھ چمکتا ہوا نکلتا تھا۔ یہاں علامتی طور پر یہ اس روحانی روشنی اور باطنی طاقت کی علامت ہے جو درویشوں کے باطن میں چھپی ہوتی ہے۔ اقبال ان اشعار کے ذریعے یہ بتاتے ہیں کہ اصل قوت، روحانی بصیرت اور عظمت اندر ہوتی ہے، نہ کہ ظاہری شان و شوکت میں۔ درویشوں کی خاموشی کے پیچھے علم و عرفان کا خزانہ چھپا ہوتا ہے۔
شعر 11: ترستی ہے نگاہ نارساء جس کے نظارے کو۔ وہ رونق انجمن کی ہے انہی خلوت گزینوں میں
تشریح: اس شعر میں اقبال اہلِ دل کی کیفیت اور ان کی اصل حقیقت کو بیان کرتے ہیں۔ “نگاہ نارساء” سے مراد وہ نظر ہے جو صرف ظاہری چیزوں کو دیکھتی ہے، جو ہمیشہ محفلوں میں رونق اور ظاہری جمال کو دیکھنا چاہتی ہے۔ لیکن اقبال بتاتے ہیں کہ جو لوگ حقیقی جمال کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، وہ دراصل ان خلوت گزینوں میں چھپے ہوتے ہیں جو محفلوں سے دور، تنہائی میں عبادت یا غور و فکر میں مشغول رہتے ہیں۔ “رونق انجمن” عام طور پر وہ شخصیت ہوتی ہے جو محفل کی تمام تر توجہ حاصل کرتی ہے، لیکن اقبال بتاتے ہیں کہ اصل جواہر وہی ہیں جو عوامی سطح پر نہیں نظر آتے۔ ان کا جمال اندر کی دنیا میں چھپاہوتا ہے اور وہ خلوت میں اپنی روحانی تسکین حاصل کرتے ہیں۔ یہ شعر صوفیانہ مفہوم رکھتا ہے کہ جو لوگ اپنی باطنی دنیا میں گہرائی سے جیتے ہیں، وہ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے شعلے کی طرح جلاتے ہیں۔
شعر 12: کسی ایسے شرر سے پھونک اپنے خرمن دل کو۔ کہ خورشید قیامت بھی ہو تیرے خوشہ چینوں میں
تشریح: یہ شعر علامہ اقبال کی روحانی بصیرت اور محبت کے عروج کو ظاہر کرتا ہے۔ “خرمن دل” سے مراد انسان کا دل ہے، جس میں محبت اور جذبے کا غلہ چھپا ہوتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اپنے دل کو ایسی آگ سے جلا، ایسی محبت سے سرفراز کر، جو نہ صرف اس کے اندر کی دنیا کو روشن کرے، بلکہ قیامت کے دن کی روشنی بھی تیری محبت کے سامنے مدھم ہو جائے۔ “خورشید قیامت” قیامت کے دن کا سورج ہے، جو تمام کائنات کو اپنی روشنی سے جلاتا ہے۔ اقبال یہاں اس بات کو بیان کر رہے ہیں کہ جب انسان اپنی حقیقت کو پہچان لیتا ہے اور حقیقی محبت و قربانی میں جیتا ہے، تو اس کی تاثیر اتنی عظیم ہوتی ہے کہ وہ کائنات کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔یہ شعر انسان کے اندر کی انفعالی طاقت کو ظاہر کرتا ہے، جس میں وہ اپنے دل کو جلا کر دنیا کو نئی روشنی دے سکتا ہے۔
شعر 13: محبت کے لئے دل ڈھونڈ کئی ٹوٹنے والا۔ یہ وہ مے ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں
تشریح: یہ شعر اقبال کی اس نظر کا عکاس ہے کہ محبت ایک نہایت قیمتی اور نازک شے ہے۔ “مے” کا لفظ یہاں عشق اور محبت کی علامت کے طور پر استعمال کیا گیا ہے، اور “آبگینوں” سے مراد وہ نازک برتن ہیں جن میں یہ مے رکھی جاتی ہے، جو اسے محفوظ رکھتے ہیں۔ اقبال اس شعر میں بتاتے ہیں کہ محبت ان لوگوں کے دلوں میں جڑتی ہے جو نرم اور حساس ہوتے ہیں۔ محبت کا جمال اسی میں ہے کہ انسان اسے بڑی احتیاط اور عزت کے ساتھ اپنے دل میں رکھے، کیونکہ یہ نہایت نازک ہے اور ہر کسی کے بس کی بات نہیں کہ وہ اسے سمجھ سکے۔ یہ شعر دراصل محبت کی عظمت اور اس کی نزاکت کو اجاگر کرتا ہے، اور اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ جو لوگ محبت کی گہرائیوں میں غوطہ زن ہیں، وہ ہی اس کے حقیقی رازوں کو جان پاتے ہیں۔
شعر 14: سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق۔ بھلا اے دل! حسین ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں
تشریح: اقبال اس شعر میں عشق کی انتہائی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب کوئی عاشق کسی کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، تو وہ خود بھی اس کے حسن سے متاثر ہو کر اپنی شخصیت میں ایک نیا حسن پیدا کر لیتا ہے۔ عشق میں وہ شخص اپنے محبوب کی خصوصیات، جمال، اور خوبیوں کا عکس بن جاتا ہے۔
“سراپا حسن بن جاتا ہے” یعنی وہ عاشق خود کو ایسے کسی حسین کی طرح محسوس کرتا ہے، جو دنیا کا سب سے بہترین جمال رکھتا ہو۔ اقبال یہاں حسن کی ایک اور سطح کو بیان کرتے ہیں، جس میں نہ صرف ظاہری جمال بلکہ روحانی جمال بھی شامل ہے۔ یہ شعر دراصل اقبال کے فلسفہ عشق کا اظہار ہے، جس کے مطابق محبت اور عشق انسان کی ذات کو ایک نیا رنگ دیتے ہیں، اور وہ اپنی حقیقت کے مطابق جمال میں ڈھل جاتا ہے۔
شعر 15: پھڑک اٹھا کوئی تیری ادائے ما عرفنا پر۔ ترا رتبہ رہا بڑھ چڑھ کے سب ناز آفریںوں میں
تشریح: اس شعر میں اقبال محبوب کی ایسی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں کہ جب وہ اپنی قدرتی یا کسی غیر معمولی ادا سے کسی کو متاثر کرتا ہے، تو وہ شخص اس کی عظمت کو پہچان لیتا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اس غیر معمولی انداز اور خصوصیت کی بدولت محبوب کی عظمت ہر نگاہ میں بڑھ جاتی ہے۔ یہاں “ناز آفریں” سے مراد وہ خوبصورتی، شان اور عزت ہے جو محبوب کی فطرت میں ہے اور جو اس کی ہر حرکت میں جھلک رہی ہے۔
شعر 16: نمایاں ہو کے دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا۔ بہت مدت سے چرچے ہیں ترے باریک بینوں میں
تشریح: اس شعر میں اقبال محبوب کو مخاطب کرتے ہوئے اس کی حقیقت اور جمال کی حقیقت کو اجاگر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر محبوب چاہے تو اپنے جمال کو پوری دنیا کے سامنے بے نقاب کر دے، کیونکہ اس کے جمال کے بارے میں پہلے ہی بہت سی باتیں ہو چکی ہیں۔ “باریک بینوں” سے مراد وہ لوگ ہیں جو صرف ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھتے، بلکہ ان کی گہری بصیرت اور عقلی طاقت کے ذریعے وہ اندر کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
شعر 17: خموش اے دل، بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں
تشریح: اقبال یہاں دل کی لگن اور شدت کو مصلحت اور اخلاقی آداب کے ساتھ متوازن کرنے کی بات کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ محبت میں جو سب سے ضروری چیز ہے، وہ ادب اور سلیقہ ہے۔ محفلوں میں باآداب رہنا اور اپنی محبت کو عزت و احترام کے ساتھ پیش کرنا ضروری ہے۔
شعر 18: برا سمجھوں انہیں مجھ سے تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ کہ میں خود بھی تو ہوں اقبال اپنے نکتہ چینوں میں
تشریح: اقبال یہاں اپنی شخصیت کا زبردست اشارہ دیتے ہیں۔ وہ اپنے نکتہ چینوں یا مخالفین سے کہتے ہیں کہ اگر وہ میری مخالفت کرتے ہیں یا مجھ سے برا سمجھتے ہیں، تو ان کا یہ خیال حقیقت سے متصادم ہے، کیونکہ میں خود اپنی حقیقت سے بخوبی آگاہ ہوں اور اپنی ذات کا شناسا ہوں۔ یہ شعر اقبال کی خودی کی قوت، خود اعتمادی اور حقیقت کے علم کو اجاگر کرتا ہے، جو کسی بھی بیرونی تنقید یا مخالفت سے متاثر نہیں ہوتا۔
We offer you our services to Teach and Learn Languages, Literatures and Translate. (Urdu, English, Bahasa Indonesia, Hangul, Punjabi, Pashto, Persian, Arabic)
اس آرٹیکل کو بہتر بنانے میں ہماری مدد کریں
اگر آپ کو اس آرٹیکل میں کوئی غلطی نظر آ رہی ہے۔ تو درست اور قابلِ اعتبار معلومات کی فراہمی میں ہماری مدد کریں۔ ہم درست معلومات کی ترسیل کے لیے سخت محنت کرتے ہیں ۔ (علمو) اگر آپ بھی ہمارے ساتھ معلومات کا تبادلہ کرنا چاہتے ہیں تو ہماری اس کمیونٹی میں شامل ہو کر معلومات کے سلسلے کو بڑھانے میں ہماری مدد کریں۔ ہمارے فیس بک ، وٹس ایپ ، ٹویٹر، اور ویب پیج کو فالو کریں، اور نئی آنے والی تحریروں اور لکھاریوں کی کاوشوں سے متعلق آگاہ رہیں۔
Follow us on
Related
Discover more from HEC Updates
Subscribe to get the latest posts sent to your email.